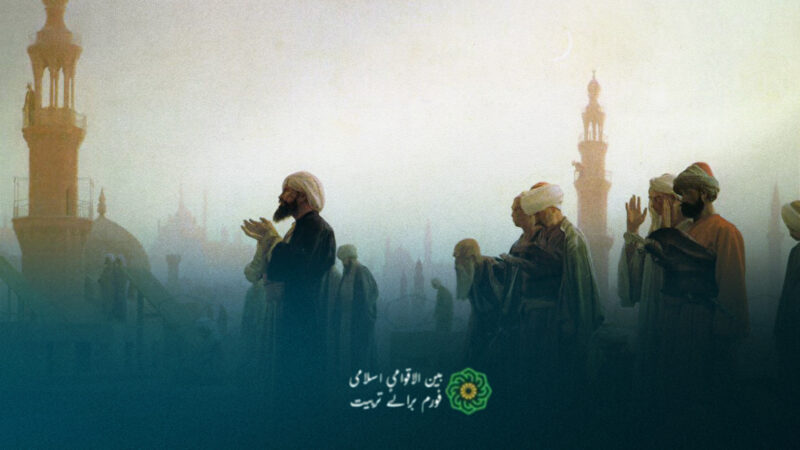تواضع (عاجزی) ایک پسندیدہ وصف ہے جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معزز صحابہؓ کی صفات میں سے ہے۔ اسی لیے علماء اور مربی تواضع اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ علم و فہم کی گہرائی ہے، اور علم تکبر کے ساتھ نہیں چل سکتا اور نہ ہی فہم گناہ کا ہمراہی ہوتا ہے، بلکہ ان کی نشو ونما تقویٰ کے ذریعے ہوتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ تواضع ایسی بہترین صفت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رضامندی بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ متواضع شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس سے مانوس ہوتے ہیں اور اس پر بھروسا کرتے ہیں۔ عجز دراصل یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر برتری اور تکبر چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا حقیقی مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی طرف احترام اور قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے دولت، مرتبہ، علم یا کسی اور معاملے میں ان کے درجات مختلف ہوں۔
تواضع کے لغوی و اصطلاحی معنی:
علماء کے نزدیک عاجزی کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے اس کے لغوی معنی کو دیکھنا ضروری ہے۔ لغت میں، تواضع کا مطلب ہے: کسی نے خود کو نیچا کیا، یعنی اس نے اپنی نفس کو عاجز بنایا۔ تواضع الرجل کا مطلب ہے: جب کوئی شخص عاجزی اختیار کرے، یعنی “وہ جھک گیا اور خشوع اختیار کیا”۔
اصطلاحی طور پر عاجزی کا مطلب ہے: “سربراہی چھوڑ دینا، اپنے آپ کو غیر معروف ظاہر کرنا، بڑائی اور زیادہ عزت و اکرام کو ناپسند کرنا، خود پسندی اور تکبر سے پرہیز کرنا اور اپنی خوبیوں پر فخر کرنے، جاہ و مال پر تفاخر کرنے سے بچنا”۔
کہا گیا ہے کہ عاجزی یہ ہے: “انسان کا اس درجے پر راضی رہنا جو اس کے فضل اور مقام سے کم ہو”۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے: “کسی کے سامنے اس کی بڑائی کے اعتراف میں خود کو نیچا ظاہر کرنا”۔ نیز، “اس شخص کی تعظیم کرنا جو فضیلت میں بلند ہو”۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں تواضع کی اہمیت:
قرآن کریم نے علماء، مربیوں اور دیگر افراد کی عاجزی کی صفت کی تعریف کی ہے، جو اس عظیم خُلق کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
“رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں” [الفرقان: 63]
ابن قیمؒ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا:
یعنی سکون اور وقار کے ساتھ، عاجزی کرنے والے، نہ اترانے والے اور نہ تکبر کرنے والے۔
حسن بصریؒ نے کہا:
“وہ علماء اور بردبار لوگ ہیں۔”
محمد بن حنفیہؒ نے فرمایا:
“وہ وقار اور پاکدامنی والے لوگ ہیں، بیوقوفی نہیں کرتے، اور اگر ان پر بیوقوفی کی جائے تو وہ حلم سے کام لیتے ہیں۔”
آیت میں لفظ ھون آیا ہے۔ ھون (زبر کے ساتھ) لغت میں نرمی اور ملائمت کو کہتے ہیں، جبکہ ھون (پیش کے ساتھ) ذلت و خواری کو کہتے ہیں۔
لہٰذا، زبر کے ساتھ “ھون” اہلِ ایمان کی صفت ہے، اور پیش کے ساتھ “ھون” اہلِ کفر کی صفت ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا آگ ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مومنین کے لیے نرم رویہ اختیار کریں اور ان کے ساتھ عاجزی برتیں۔ چنانچہ فرمایا:
“ایمان لانے والوں کی طرف جھکو” [الحجر: 88]
قرطبیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا:
“یعنی اپنے ماننے والوں کے لیے نرم پہلو اختیار کرو اور ان کے ساتھ عاجزی کرو”
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، ان پر اور مومنین پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی امت کے لیے نرم کر دیا گیا، جو آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کی ڈانٹ کو ترک کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں۔
“اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمھارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو” [آل عمران: 159]
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی اس طرح تعریف کی کہ وہ مومنین کے لیے شفقت، مہربانی اور عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اور کافروں پر سختی، درشتی اور برتری ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا:
“اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنین پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے” [المائدہ: 54]
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ کو تمام لوگوں کے ساتھ عاجزی کا خُلق اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
“صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ کسی بندے کو معاف کرنے کے باعث عزت ہی عطا کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے” [صحیح مسلم]۔
اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اُس مقام سے نیچے کر لے جس کا وہ مستحق ہے، صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کی امید میں، بغیر کسی اور غرض کے۔ بلکہ وہ اللہ کے لیے خالص بندگی اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی اور اس کی ممانعت سے رکنے کے لیے، اور اپنی نفس کی حقارت کو دیکھتے ہوئے خود پسندی کو دور کرتا ہے۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان (جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے) کے بارے میں دو پہلو بیان کیے ہیں:
(الف) اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس کے عاجزی کے بدلے میں عزت عطا کرتا ہے، اور اس کی عاجزی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت، مقام اور عزت پیدا کرتی ہے۔
(ب) یہ کہ آخرت میں اس کے عاجزی کے بدلے میں اس کا اجر بلند درجات کی صورت میں ہوگا۔
حضرت عیاض بن حمارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
“بے شک اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے”۔ [مسلم]
یعنی ہر شخص دوسرے کے لیے عاجزی اختیار کرے، اور اس پر برتری نہ جتائے، بلکہ اسے اپنے برابر سمجھے یا اس سے بھی زیادہ عزت دے۔
سلف صالحین رحمہم اللہ کی عادت یہ تھی کہ
جو ان سے چھوٹا ہوتا، اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے۔
جو بڑا ہوتا، اسے اپنے والد کی طرح عزت دیتے۔
اور جو ہم عمر ہوتا، اسے اپنے بھائی کی طرح سمجھتے۔
چنانچہ وہ اپنے سے بڑے کو عزت و تعظیم کی نظر سے دیکھتے، اپنے سے چھوٹے پر شفقت و رحمت کی نظر ڈالتے، اور اپنے برابر والے کو برابری کی نظر سے دیکھتے، یوں کوئی کسی پر زیادتی نہ کرتا۔
صحابہ کرامؓ نے اس خُلق (عاجزی) کو اپنے دلوں میں بسا لیا تھا۔ چنانچہ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ ، جو اپنے محلے کے لوگوں کی بکریوں کا دودھ دوہتے تھے۔ جب انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تو محلے کی ایک لونڈی نے کہا: اب وہ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہیں گے۔
حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات سن لی اور فرمایا: “کیوں نہیں، میں تمہاری بکریوں کا دودھ ضرور دوہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس معاملے میں داخل ہوا ہوں، وہ میرے اس خُلق کو نہیں بدلے گا جس پر میں تھا۔” چنانچہ وہ ان کے لیے دودھ دوہتے رہے۔
حضرت ابو صالح غفاریؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ رات کے وقت مدینے میں ایک نابینا عورت کی خبرگیری کرتے تھے اور اس کے معاملات کو سنبھالتے تھے۔
چنانچہ جب بھی وہ اس کے پاس پہنچتے تو کسی اور کو پہلے سے اس کے کام کرتے ہوئے پاتے۔
آخرکار حضرت عمرؓ نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ ہیں، جو خفیہ طور پر اس کے پاس آتے اور اس کی ضروریات پوری کرتے تھے، حالانکہ وہ خلیفہ تھے۔
سعد بن حسن تمیمیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا حال یہ تھا کہ ان کی عاجزی اور سادگی کے باعث انہیں ان کے غلاموں میں بھی پہچاننا مشکل ہوتا تھا، یعنی وہ لباس میں اس قدر عاجزی اختیار کرتے تھے کہ کوئی فرق معلوم نہ ہوتا۔
علماء کے تواضع کی مثالیں:
کتبِ تراث نے ہمارے لیے علماء کے درمیان عاجزی کی کئی تربیتی مثالیں محفوظ کی ہیں۔ ان میں امام مالک بن انسؒ نے عاجزی کے خُلق کو مجسم کرنے کی بہترین مثالیں پیش کیں۔ ابن عبد البر نے ان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: جب ابو جعفر المنصور نے حج کیا تو مجھے بلایا۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے بات کی اور اس کے سوالات کے جواب دیے۔ اس نے کہا: “میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی یہ کتابیں، جو آپ نے مرتب کی ہیں — یعنی الموطأ — ان کی نقول تیار کرواؤں، پھر مسلمانوں کے ہر شہر اور علاقے میں ایک ایک نسخہ بھیجوں اور انہیں حکم دوں کہ وہ صرف اسی پر عمل کریں، اس کے علاوہ کسی اور علم کی طرف نہ جائیں، اور اس نئے پیدا شدہ علم کو چھوڑ دیں؛ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ علم کی اصل مدینے کے لوگوں کی روایت اور ان کا علم ہے”۔
امام مالک نے کہا: “اے امیر المؤمنین، ایسا نہ کریں؛ کیونکہ لوگوں تک مختلف اقوال پہنچ چکے ہیں، انہوں نے احادیث سن رکھی ہیں، روایات بیان کر رکھی ہیں، اور ہر قوم نے جو کچھ ان تک پہنچا، اسی کو لے لیا ہے، اسی پر عمل کیا ہے اور اسی کو دین مانا ہے، صحابہ کرامؓ اور دیگر لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے، ان کو اس سے پھیرنا مشکل ہے، اس لیے لوگوں کو اسی حال پر چھوڑ دیں، جسے ہر علاقے کے لوگوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔”
اس پر ابو جعفر نے کہا: “میری جان کی قسم، اگر آپ میری بات مان لیتے تو میں یہی حکم دے دیتا”۔ اس قصے کے راوی نے کہا:” یہ بات انصاف کی انتہا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے!”
اسی طرح عبد الرحمن بن القاسم سے روایت ہے کہ انہوں نے امام مالکؒ سے کہا: “میں کسی کو نہیں جانتا جو اہلِ مصر سے زیادہ بیوع (خرید و فروخت) کے مسائل کا علم رکھتا ہو”۔ امام مالکؒ نے ان سے کہا: “کس بنیاد پر آپ ایسا کہتے ہیں؟” انہوں نے کہا: “آپ کی وجہ سے”۔ امام مالکؒ نے جواب دیا: “مجھے خود بیوع کا علم نہیں، تو وہ اسے میرے ذریعے کیسے جان سکتے ہیں”
رجاء بن حیوہ نے کہا: میں ایک رات عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس بیٹھا تھا کہ چراغ مدھم ہو گیا۔ میں نے کہا: “کیا میں اس غلام کو نہ جگا دوں تاکہ وہ اسے درست کر دے؟”
عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا:” نہیں، اسے سونے دو”۔
میں نے کہا: “تو کیا میں خود ہی اسے ٹھیک کر دوں؟”
انہوں نے فرمایا: “نہیں، کسی مہمان کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اپنے میزبان سے خدمت لے”۔
پھر وہ خود اٹھے، چراغ کو ٹھیک کیا اور اس میں تیل ڈالا، پھر واپس آئے اور کہا: “میں اٹھا بھی تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور واپس آیا بھی تو عمر بن عبدالعزیز تھا”۔
اور امام اوزاعی نے کہا: عمر بن عبدالعزیزؒ روزانہ اپنی ذاتی دولت سے ایک درہم مسلمانوں کے کھانے میں خرچ کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔
عمر بن عبدالعزیز کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے نے ایک ہزار درہم میں ایک انگوٹھی خریدی ہے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا: “جب میرا یہ خط تمہیں ملے تو انگوٹھی بیچ دو، اور اس رقم سے ایک ہزار بھوکوں کو سیر کرو، اور دو درہم کی ایک انگوٹھی بنوا لو، اور اس کا نگ چینی لوہے کا ہو، اور اس پر یہ عبارت کندہ کروا دو: “اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی اوقات کو پہچانا۔”
عطاء بن أبي رباح نے کہا: “بسا اوقات کوئی شخص مجھے حدیث سناتا ہے تو میں اس کی بات پوری توجہ سے سنتا ہوں، گویا کہ میں نے اسے کبھی نہیں سنا، حالانکہ میں نے وہ حدیث اس کی پیدائش سے پہلے ہی سن رکھی ہوتی ہے”۔
ابو عیسی الحواري نے کہا: جب سفیان ثوریؒ رملہ یا بیت المقدس پہنچے تو ابراہیم بن ادہمؒ نے ان کے پاس پیغام بھیجا: آئیں ہمیں حدیث سنائیں۔
کسی نے ابراہیم بن ادہم سے کہا: “اے ابو اسحاق! آپ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں”؟
انہوں نے کہا: “میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا عاجزی کرتے ہیں”۔
چنانچہ سفیان ثوریؒ آئے اور انہیں حدیث سنائی۔
عبد الرزاق بن همام نے روایت کی: میں نے سفیان الثوریؒ کو صنعاء یمن میں دیکھا کہ وہ ایک بچے کو حدیث لکھوا رہے تھے اور اس سے سن کر تصحیح کروا رہے تھے۔
ابو بكر الخلال نے کہا: میں نے ابو عبد الله، احمد بن حنبلؒ کو دیکھا کہ وہ بازار سے خود روٹی خریدتے اور اسے تھیلی میں ڈال کر لے جاتے، اور کئی بار میں نے انہیں باقلاء خریدتے دیکھا، وہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے اور اپنے بیٹے عبد الله کا ہاتھ پکڑے ہوتے۔
اسماعيل بن إسحاق السراج نے کہا: میں نے ابو عبد الله، احمد بن حنبلؒ سے پہلی ملاقات میں کہا: اے ابو عبد الله، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا سر چوم لوں۔
انہوں نے کہا: “میں اس قابل نہیں ہوں”۔
عمر بن علي البزار نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہؒ کے بارے میں کہا: “جب ہم ان کے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے تو وہ خود اپنی کتاب اٹھاتے اور ہمیں اسے اٹھانے نہ دیتے”۔
میں ان سے معذرت کرتا کہ کہیں یہ بدتمیزی نہ سمجھیں، تو وہ فرماتے: “اگر میں اسے اپنے سر پر بھی اٹھا لوں تو یہ مناسب ہے، کیا میں اس چیز کو نہ اٹھاؤں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں؟”
علماء اور مربیوں میں تواضع ایک عمدہ صفت ہے جو دلوں کو مسخر کر لیتی ہے، لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیتی ہے اور انہیں اسلامی تعلیمات قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔
یہ ایک ایسا خُلق ہے جو علم، تقویٰ اور دوسروں کی رائے کے احترام سے حاصل ہوتا ہے، اور اپنے حاملین کو عزت و وقار عطا کرتا ہے، اسے بلند مرتبہ اور عظمت بخشتا ہے، اور فخر و مباہات کی مشقت سے نجات دلاتا ہے۔
تواضع حق کے سامنے جھکنے اور اسے قبول کرنے کا نام ہے، اور یہی اصل عزت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت اور حق کی طرف رجوع ہے، اور اس میں دین و دنیا دونوں کی مصلحت ہے، نیز یہ لوگوں کے درمیان بغض و کینہ کو ختم کرتا ہے۔
مصادر:
الفراهيدي: العين 2/196.
الزبيدي: تاج العروس 22/343.
الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 299.
الجاحظ: تهذيب الأخلاق، ص 25.
ابن حجر: فتح الباري 11/341.
ابن القيم: مدارج السالكين 3/108.
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 10/56.
الشوكاني: فتح القدير 2/75.
القاضي عياض: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 8/59.
ابن سعد: الطبقات الكبرى 3/ 138:139.
ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2/ 265.
ابن أبي الدنيا: التواضع والخمول، ص 185.
أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء 1/60.
ابن سعد: الطبقات الكبرى 3/20.
مالك بن أنس: الموطأ 1/33.
ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 1/533.
ابن كثير: البداية والنهاية 9/2011.
الذهبي: سير أعلام النبلاء 5/86.
محمد بن مفلح الحنبلي: الآداب الشرعية 2/258.
البزار: الأعلام العلية، ص 52.
مترجم: زعیم الرحمان